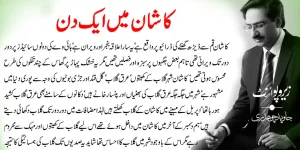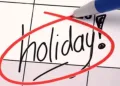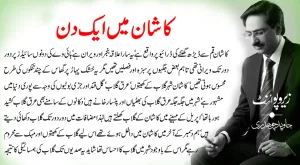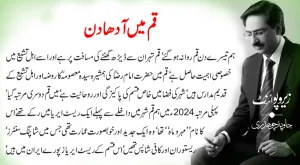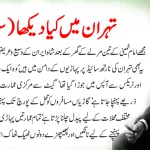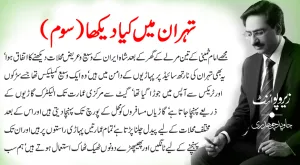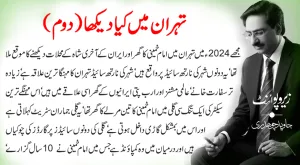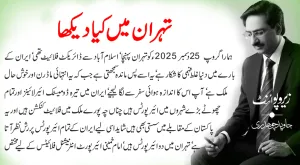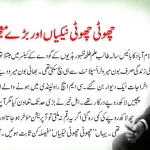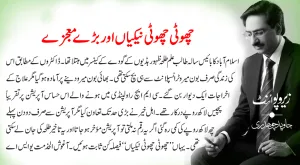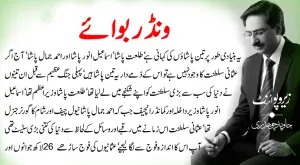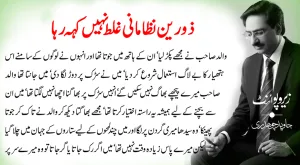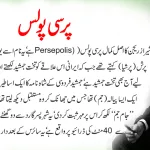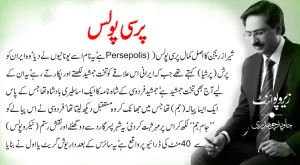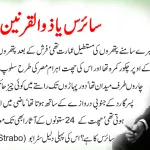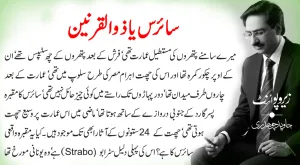موت پہلے کان پر وار کرتی ہے‘ انسان کان سے مرنا شروع ہوتا ہے‘ یہ حقیقت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میں مر رہا تھا‘ میرے ہاتھ میں آئس کریم کی کون تھی‘ جسم کے آر پار سوراخ تھے‘ میرے بدن سے لہو ابل رہا تھا‘ آنکھیں سوجھ چکی تھیں اور ٹانگیں‘ جی ہاں! ٹانگیں بے جان ہوتی جا رہی تھیں‘ میں اپنے پاؤں پر گر رہا تھا‘ میرا خون ابل ابل کر جوتوں میں گھس رہا تھا‘ میرے دائیں بائیں موجود لوگ چیخ رہے تھے‘ کسی کا بازو نہیں تھا‘ کوئی ٹانگوں سے محروم تھا‘ کسی کا سر غائب تھا اور کسی کے پیٹ سے انتڑیاں باہر لٹک رہی تھیں‘ یہ سب لوگ رو رہے تھے‘ چیخ رہے تھے لیکن میں انہیں صرف دیکھ سکتا تھا‘ میں ان کی چیخوں کو صرف محسوس کر سکتا تھا‘ سن نہیں سکتا تھا‘ کیوں؟ کیونکہ میرے کان مر چکے تھے‘ میں سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا اور ہاں ایک اور چیز‘ ایک اور حقیقت! مرتے ہوئے انسان کو درد بھی نہیں ہوتا‘ یہ تکلیف کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے‘ میرے جسم میں درجنوں چھید تھے اور ہر چھید سے خون ابل رہا تھا مگر مجھے کوئی چھید تکلیف نہیں دے رہا تھا‘ مجھے جسم کے کسی کونے‘ کسی حصے میں دکھ محسوس نہیں ہو رہا تھا‘ بس میری سانسیں ناہموار ہو رہی تھیں‘ سانسوں کے وقفے بڑھتے جا رہے تھے‘ جو سانس جاتا تھا‘ وہ واپس نہیں آتا تھا اور میں جب سانس کھینچنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تھا اور اس دورے کے دوران میرا حلق خون سے بھر جاتا تھا۔
میں زمین پر لیٹ گیا‘ میری ٹانگیں‘ میرے پاؤں سیدھے تھے‘ میں نے بازو بھی سیدھے کر لئے‘ میری آئس کریم کی کون ٹوٹ چکی تھی‘ میں نے مٹھی کھولی اور ٹوٹی ہوئی کون میرے ہاتھ سے پھسل گئی‘ میں نے اپنے پاؤں پر کوئی گرم سی چیز محسوس کی‘ میں نے زور لگا کر سوجھی ہوئی آنکھیں کھولیں‘ سانس روک کر زور لگایا‘ اپنی گردن اٹھائی اور پاؤں کی طرف دیکھا‘ میرے دونوں پاؤں پر تازہ انتڑیاں گری ہوئی تھیں۔ ’’انسان کے جسم میں اتنی آنتیں ہوتی ہیں؟‘‘ میرے ٹوٹے پھٹے سر میں سوال گونجا‘ مجھے اس وقت معلوم ہوا ’’انسان کا ذہن موت کے دروازے پر بھی سوال پوچھنے سے باز نہیں آتا‘ یہ مرتے مرتے بھی سوال داغ دیتا ہے‘‘ میری سانسوں کے وقفے لمبے ہوتے چلے گئے‘ میرے لئے سانس لینا مشکل ہو چکا تھا‘ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا‘ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا‘ جیسے میرا دل ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے باہر آنے کیلئے مچل رہا ہے‘ میں نے دل پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی لیکن میرے ہاتھ اور میرے بازو بے جان ہو چکے تھے‘ میں نے لمبی سانس لینے کی کوشش کی لیکن میرے پھیپھڑوں میں جان نہیں تھی‘ میں نے سانس کھینچنے کیلئے زمین پر ایڑھیاں پھنسائیں اور پورے جسم کا زور لگا کر آخری سانس کھینچا‘ سانس آیا لیکن وہ سانس میرے سینے سے نیچے نہ جا سکا‘ میرا پورا جسم پھڑپھڑایا اور پھر ساکت ہو گیا‘ میری آنکھیں بھی مر گئیں لیکن نہیں‘ آپ ایک لمحے کیلئے ٹھہر جائیے‘ میری مری ہوئی آنکھوں میں ایک منظر ابھی تک زندہ تھا‘ یہ تین سیکنڈ لمبا جاندار منظر تھا اور یہ منظر میری تدفین کے بعد بھی زندہ رہے گا اور یہ شاید اس وقت تک زندہ رہے جب تک اس زمین پر زندگی زندہ ہے‘ یہ منظر‘ یہ تین سیکنڈ کا منظر شاید آپ کیلئے اہم ہو۔
میں 27 مارچ 2016ء کی شام چھ بج کر 41 منٹ پر گلشن اقبال کے پارک میں کھڑا تھا‘ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا‘ اس کا خیال تھا‘ میں ابھی چھوٹا ہوں‘ میں ہجوم میں گم ہو جاؤں گا‘ میں نے دوسرے ہاتھ میں کون آئس کریم پکڑ رکھی تھی‘ ہم پارک میں فوارے کے قریب کھڑے تھے‘ میرے سامنے جھولا تھا‘ میں اپنی ماں کے ساتھ جھولے کے سامنے کھڑا تھا‘ ہم جب بھی اس پارک میں آتے تھے‘ میری ماں مجھے اس جھولے پر ضرور لے کر آتی تھی‘ یہ جھولا میری ماں کی کمزوری تھا‘ وہ یہ جھولا دیکھنے کے بعد مجھے ہمیشہ بتاتی تھی ’’میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو مجھے یہ جھولا بہت اچھا لگتا تھا‘ میں اس پر بیٹھنا چاہتی تھی مگر میرے ماں باپ غریب تھے‘ وہ جھولے کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے چنانچہ میں سارا دن جھولے کے قریب کھڑی ہو کر بچوں کو جھولے پر چڑھتے اور اترتے دیکھتی رہتی تھی‘ آج ہم پر اللہ کا کرم ہے لہٰذا میں چاہتی ہوں‘ میرا بیٹا جی بھر کر جھولا لے‘‘ اور میں قہقہہ لگاتا تھا‘ ماں کو تھینک یو بولتا تھا اور اس کے ہاتھ اور اس کے گالوں پر پیار کرتا تھا‘ میری ماں مجھے اس جھولے پر چڑھا دیتی تھی اور میں جب تک چاہتا‘ اس جھولے کو انجوائے کرتا تھا‘ میری ماں جھولا رکتے ہی جھولا چلانے والے کو نیا ٹکٹ پکڑا دیتی تھی‘ میں جھولے پر بیٹھا رہتا تھا جبکہ میرے دائیں بائیں بچے تبدیل ہوتے رہتے تھے‘ میں اس وقت تک جھولے پر رہتا تھا جب تک مجھے چکر نہیں آتے تھے‘ میں نے جھولے پر بیٹھے بیٹھے سیکھا‘ انسان دائروں میں ایک خاص حد سے زیادہ نہیں گھوم سکتا‘ یہ اس کے بعد چکرانے لگتا ہے اور اگر اس وقت یہ چکر روکے نہ جائیں تو پھر اس کو قے آ جاتی ہے‘ یہ الٹیاں کرنے لگتا ہے‘ میں اس حقیقت کو جان گیا تھا لہٰذا میں جھولے کے اوپر سے نعرہ لگا دیتا تھا ’’امی بس‘ اب بس‘‘ اور میری ماں مجھے نیچے اتار لیتی تھیں۔
ہم اس دن بھی جھولے کے سامنے کھڑے تھے‘ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے‘ جھولا دائرے میں گھوم رہا تھا اور بچے خوشی سے قہقہے اور نعرے لگا رہے تھے‘ ہمارے گرد ہجوم تھا‘ اتوار کی شام عموماً اس جگہ رش ہو جاتا ہے‘ پارک میں دائیں بائیں کی تمام آبادیوں کے بچے یہاں آ جاتے ہیں‘ یہ بچے جھولے بھی لیتے ہیں‘ گھاس پر دوڑتے‘ بھاگتے اور قلابازیاں بھی کھاتے ہیں اور لوگ فیملیوں کے ساتھ مختلف جگہوں اور مقامات پر پکنک بھی مناتے ہیں یوں اتوار کے دن یہ پارک‘ پارک نہیں رہتا‘ پکنک سپاٹ بن جاتا ہے اور میں اور میری ماں ہر اتوار کی شام اس پکنک سپاٹ میں ملکہ اور شہزادے کی طرح داخل ہوتے تھے‘ 27 مارچ کی شام وہاں رش تھا‘ وہاں بچے بھی تھے‘ بچوں کی مائیں بھی‘ باپ بھی‘ بہن بھائی بھی اور پاپ کارن‘ کون آئس کریم‘ مونگ پھلی‘ چنے‘ جوس‘ پانی اور چھلیاں بیچنے والے بھی‘ یہ لوگ بچوں کو متوجہ کرنے کیلئے آوازیں لگا رہے تھے‘ میں نے کون آئس کریم کی مشین دیکھی تو میں نے ماں کا ہاتھ دبا دیا‘ ماں میرا اشارہ سمجھتی تھی‘ وہ کون آئس کریم کی ریڑھی پر گئی اور اس نے مجھے کون خرید دی‘ میں نے ایک ہاتھ میں کون پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ پکڑ کر جھولے کے قریب پہنچ گیا‘ جھولا جھول رہا تھا‘ وہ دائرے میں بھی گھوم رہا تھا اور اوپر سے نیچے بھی آتا تھا‘ ہم ماں بیٹا وہاں کھڑے ہو گئے‘ بچے خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے‘ لڑکے اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور ماں باپ ان کے ساتھ خوش ہو رہے تھے‘ خوانچے والے آوازیں لگا رہے تھے‘ جھولا گھرر گھرر کی آوازوں کے ساتھ گھوم رہا تھا‘ میں نے اچانک کسی کے دوڑنے کی آواز سنی‘ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا‘ ایک نوجوان وحشیانہ انداز سے ہماری طرف دوڑ رہا تھا‘ اس کے چہرے پر وحشت بھی تھی اور تشنج بھی‘ وہ چیخ رہا تھا‘ میں سب کو مار دوں گا‘ کلمہ پڑھ لو‘ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے‘ لوگ خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگے‘ وہ دوڑتا دوڑتا فوارے کے پاس آیا‘ اس نے کلمہ پڑھا‘ وہ تھوڑا سا نیچے جھکا‘ ایک خوفناک دھماکہ ہوا‘ فضا میں بدبودار دھواں پھیلا اور میرے کان مر گئے‘ میں اب دائیں بائیں بکھری آوازیں نہیں سن سکتا تھا‘ میری آنکھیں بھی دھندلا گئیں‘ میں نے زور لگا کر پلکیں اٹھائیں اور دائیں بائیں دیکھا‘ میرے ایک ہاتھ میں کون تھی‘ آئس کریم اڑ چکی تھی‘ دوسرے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ تھا لیکن ماں وہاں نہیں تھی‘ وہ قیمہ بن کر فضا میں اڑ گئی تھیں‘ بس اس کا ہاتھ بچا تھا اور وہ ہاتھ اس وقت میرے ہاتھ میں تھا‘ ماں کہاں چلی گئی‘ میں نے ایک لمحے کیلئے سوچا‘ میرے اندر سے آواز آئی‘ زندگی کے آخری لمحات میں ماں میری ڈھال بن گئی تھی‘ اس نے مجھے اپنے ساتھ چپکا لیا تھا‘ وہ بارود کے ساتھ اڑ گئی‘ وہ مجھ پر قربان ہو گئی لیکن اس کی قربانی مجھے صرف تین سیکنڈ دے سکی‘ مجھ میں اور اس میں صرف تین سیکنڈ کا فاصلہ پیدا ہوا‘ میرا جسم بھی چھلنی ہو چکا تھا‘ درجنوں چھرے اور بال بیئرنگ میرے بدن سے پار ہو گئے تھے‘ میرے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے اور میں اس برستے خون میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا‘ میرے سامنے لاشیں بکھری تھیں‘ بچے جھولے پر ہی مر گئے تھے‘ ان کے کٹے پھٹے بدن جھولے سے لٹک رہے تھے‘ بازو تھے تو ہاتھ نہیں تھے‘ ٹانگیں تھیں تو پاؤں نہیں تھے‘چہرے تھے تو آنکھیں نہیں تھیں‘ آنکھیں تھیں تو ان میں نور نہیں تھا‘ پیٹ اور گردنیں سب کی پھٹی ہوئی تھیں‘ میں نے ہر طرف انتڑیاں جھولتی اور نسیں بکھری دیکھیں‘ میرے سامنے موجود ہر آنکھ ابلی ہوئی تھی‘ ہر چہرہ ادھڑا ہوا تھا اور ہر جسم نامکمل تھا‘ لوگ دہائیاں دے رہے تھے لیکن میں ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا‘ شاید وہ بھی اپنی آوازیں نہ سن سکتے ہوں ان کے کان بھی یقیناًمر چکے ہوں گے‘ میں نے ان تین سیکنڈز میں لوگوں کو زمین پر گھسٹتے بھی دیکھا‘ زندگی کی بھیک مانگتے بھی دیکھا اور موت سے بچ کر بھاگتے بھی دیکھا‘ میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ خون میں ڈوبتا جا رہا تھا‘ میری ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں‘ مجھے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی‘ میں تھوڑا سا جھکا اور زمین پر گر گیا‘ کھلا آسمان اس وقت میرے سامنے تھا‘ آسمان پر دھوئیں کا بادل تھا‘ بادل اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا‘ پرندے بے چینی سے‘ بے تابی سے اڑ رہے تھے‘ درختوں کی ٹہنیوں سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بال لٹک رہے تھے‘ جھاڑیوں میں آنکھیں‘ ناک اور کان الجھے پڑے تھے‘ خون کی بو بارود کی بو میں مل کر ناگوار ہو رہی تھی‘ یہ فضا سے آکسیجن کم کر رہی تھی‘ مجھے اس وقت گلشن اقبال کے پارک میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی‘ میری زندگی کے آخری تین سیکنڈ فلم بن کر میری پتلیوں میں نقش ہو گئے۔
میں مر چکا ہوں‘ میری لاش پہلے ہسپتال لائی گئی‘ پھر سرد خانے میں رکھی گئی‘ میرا ماموں مجھے تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ گیا‘ اس نے مجھے پہچان لیا‘ وہ مجھے لے گیا‘ میرا جنازہ ہوا اور پھر مجھے مٹی میں دفن کر دیا گیا‘ میں اب مٹی کا رزق بن رہا ہوں لیکن میری زندگی کے آخری تین سیکنڈ اب بھی زندہ ہیں‘ کاش کوئی آئے‘ میری قبر کھولے‘ میری بند پتلیاں اٹھائے اور میری بے نور آنکھوں میں جھانک کر دیکھے‘ اسے وہاں تین سیکنڈ کی اس فلم کے ساتھ ایک سوال بھی رکھا ہوا ملے گا‘ یہ چھوٹا سا معصوم سا سوال ہے ’’دنیا کے جس معاشرے میں بچوں کو بارود سے اڑا دیا جائے‘ کیا اس معاشرے کو معاشرہ کہنا چاہیے‘‘ میں نے مرنا تھا‘ میں مر گیا‘ مجھے اپنی موت کا جواب نہیں چاہیے‘ میں بس اس سوال کا جواب چاہتا ہوں ’’کیا یہ معاشرہ معاشرہ ہے‘‘۔
ستائیں مارچ

آج کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبریں
آج کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبریں
-
حکومت کا شب برات پر عام تعطیل کا اعلان
-
شتروگھن سنہا نے 16 ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرلی
-
کاشان میں ایک دن
-
پی ٹی آئی کے سینئر رہنما و سابق رکن قومی اسمبلی انتقال کر گئے
-
عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں 500 ڈالرکی کمی
-
مسلسل دو روز ہوشربا اضافے کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت میں حیران کن کمی
-
عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں حیران کن اضافہ، پاکستان میں قیمت میں بھی ہوشربا اضافہ متوقع
-
خطرے کی گھنٹی بج گئی الرٹ جاری
-
پاکستان سونے کی قیمت میں حیران کن اضافہ
-
جویریہ عباسی کا شوہر کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ؛ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا
-
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان
-
پشاور چھوڑ کر جارہا ہوں، غلام احمد بلور کا انتخابی سیاست سے علیحدگی کا اعلان
-
عمران خان کو پمز ہسپتال لایا گیا، حکومت کی تصدیق،عمران خان کو آنکھوں کی کونسی بیماری ہو گئی ہے؟حیر...
-
زلزلے کے جھٹکے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے